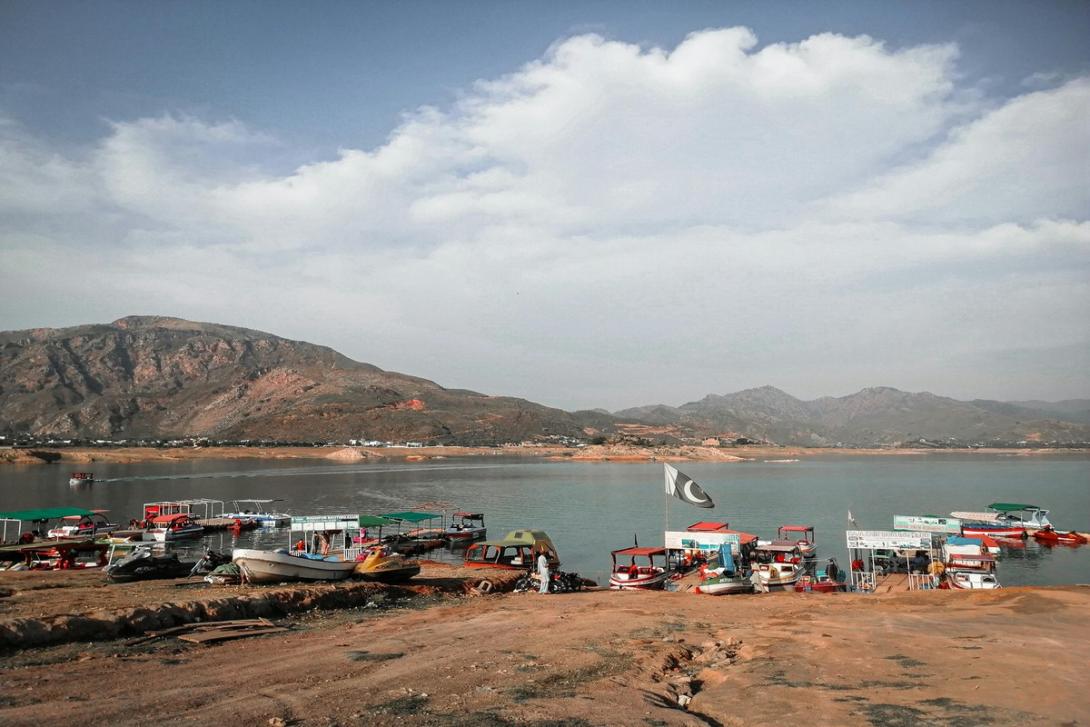اہل مغرب نے مذہب کو افیون قرار دیا، جس کے معنی یہ تھے کہ مذہب تعمیر وترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ اپنے ماننے والے کو دنیا کے کاروبار سے الگ تھلگ کردیتا ہے۔ اہل مغرب کی مذہب کے تعلق سے اس رائے کا پس منظر اہل کلیسا کے ظالمانہ رویے ہیں، جن کی وجہ سے بجا طور پر مذہب کو ایک غیر مفید چیز سمجھا گیا۔ لیکن مذہب کے بارے میں یہی تاثر اسلام پر بھی چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی اور دنیا کے سامنے یہ باور کرایاگیا کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب سے مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے ماننے والے کو کاروبار دنیا سے الگ تھلگ کردیتا ہے اور دنیا کی تعمیر وترقی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماضی کی صدیوں میں مسلمانوں کی سیاسی اور علمی پسپائی اور زوال پذیری نے گویا دنیا والوں پر عینی شہادت پیش کردی کہ واقعی اسلام زمانے کا ساتھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا اور وہ ازکار رفتہ مذہب ہے۔ رواں صدی میں نائن الیون کے بعد اسلام کی افادیت و حرکیت کے بارے میں خود مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں ۔ اس مضمون میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے کہ اسلام میں زمانے کی تعمیر وترقی کی کتنی صلاحیت ہے اور انسانوں کی روحانی، اخلاقی اور مادی رہنمائی کی کیا اہلیت ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنے ماننے والوں کو کس درجہ حرکی (Dynom ic) اور فعال بناتا ہے۔
اسلامی تعلیمات بنیادی طور پر چار اجزاء میں منقسم ہیں : عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق۔
اسلام میں خدا کا تصور
دنیا کے اکثر مذاہب میں خدا اور معبود کو بے جان مجسموں، تصاویر اور یادگاروں میں تلاش کیاگیا یا بعض مرے ہوئے یا غیر موجود انسانوں کی طرف الوہیت کی نسبت کی گئی اور پھر اس کی عبادت کے لیے ایسے ہی طریقے ایجاد کیے گئے جیسے معبود اور مجسموں کے سامنے گھنٹا اورڈھول بجانا ، سیٹی اور تالی پیٹنا، اگربتی اور موم جلانا ، لوبان اور بخارات کے ذریعے معبودکو خوش کرنا وغیرہ، مگر اسلام نے ان سارے تصورات کی تردید کی اور خدائے واحد کا عقیدہ دیا، جو تمام صفات کمال و جمال سے متصف ہے، جس کااپنے بندوں سے ہروقت کا ربط وتعلق ہے اور جو خود حی وقیوم ہے جسے نیند اور اونگھ نہیں آتی۔ ہرچیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ بندوں کی نگاہوں کی چوری اور دلوں کے راز سے واقف ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے۔ وہ مضطر کی دعا کوسنتا ہلے اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ وہ نفع ونقصان کا مالک ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں وہی موت اور حیات کا مالک ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔
اسلام نے معبود کی عبادت کے جو طریقے بتائے اس میں درمیان کے تمام واسطے ختم کردیے اور براہ راست بندے کا خدا سے تعلق قائم کیا ۔ درمیان میں نہ برہمن کی ضرورت نہ پجاری کی ، نہ کاہن کی نہ ربی کی نہ حاخام کی۔ اس کے ساتھ ہی معبود کے سامنے نہ آگ جلانے کی ضرورت ہے نہ ناقوس اور گھنٹا بجانے کی۔ نہ اگربتی اور موم بتی جلانے کی، نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پوجا کے اشیائ کو سجانے کی ضرورت ہے ۔ ان تمام بیرونی اور درمیانی رسوم اور قیود کو اسلام نے ختم کیا اور براہ راست خدا سے بندے کا تعلق قائم کیا ۔ ہر شخص خود اپناکاہن، پجاری ، پادری اور برہمن ہے ۔ اسلام نے عبادت کے لیے مکان، مندر ، کلیسا، چرچ اور گرجا گھر کی قید بھی ختم کردی اور پوری سطح زمین کو سجدہ گاہ قرار دیا۔ بحر وبر اور سفر وحضر ہر جگہ اور ہر حالت میں معبود کی عبادت ہوسکتی ہے۔
اسلامی عقیدۂ توحید کے حرکی تصور کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس میں معبود کو بندہ ہر لمحے اپنی شہ رگ سے زیادہ قریب پاتا ہے اور امن وسکون اور پریشانی و مشکل میں ہر وقت وہ اس کو پکارتا ہے۔ گنہگار سے گناہگار فرد بھی رجوع الی اللہ کرسکتا ہے اور اپنی خطائوں اور لغزشوں کی توبہ و انابت کرکے آیندہ بہتر زندگی گزارنے کا عہد کرسکتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے : ’’اگر بندہ اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ ایک بالشت چلتا ہے تو خدا اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے ۔ اگر وہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو خدا ایک گز چلتا ہے۔ اگر وہ اپنے معبود کی طرف چل کر آتا ہے تو خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میںذکر الٰہی کو زندگی اور خدافراموشی کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:
مثل الذی یذکر ربہ والذی لایذکر مثل الحی والمیت۔ ﴿بخاری﴾
’’اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا مردہ اور زندہ کی ہے ﴿اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے جبکہ یاد نہ کرنے والا مردہ ہے‘‘۔
انسان اپنے مصائب ومشکلات میں ایک ایسی ذات کی طرف رجوع کرنے کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے جو اس کی پریشانیوں کو دور کردے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی پکار کو مضطر کے لیے تمام مشکلات کا حل بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:
أَمَّن یُجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اذَا دَعَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوئ َ۔﴿النمل:۶۲﴾
’’کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے‘‘۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین بندے کو نہ صرف جمود و تعطل سے بچاتا ہے، بل کہ اس کو فاسد اور باطل فکر وعقیدے کی کھائیوں میں گرنے اور دُنیوی مایوسیوں اور ناامیدیوں کے سمندر میں غرق ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں ہر وقت امید کا چراغ جلائے رکھتا ہے اوراسے دعوت عمل دیتا ہے ۔
عقیدۂ آخرت اور انسانی زندگی
دنیا میں ہزاروں افکار و نظریات ہیں جن کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے۔ لیکن ان کے لائحہ عمل کا دائرہ اور سرگرمیوں کی سرحد اسی دنیوی زندگی تک محدود ہے ۔ اسلام نے زندگی کے دائرے کو موت کے بعد وسیع کرکے اپنے لائحہ عمل اور سرگرمیوں کا دائرہ بھی بعدالموت وسیع کردیا اور دنیا کو مزرعۃ الآخرۃ قرار دیا۔ دنیاکو فصل بونے کی جگہ قرار دینا، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ انسان فصل کی نوعیت اور قسم کا انتخاب خود کرے۔ اور معیار و مقدار بھی اسی کے دائرۂ انتخاب میں رکھا، تاکہ وہ فصل کاٹنے کے بعد کسی دوسرے کا گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ فصل بونے اور کاٹنے کی تمثیل میں کھیت کو ہم وار کرنے، بیج کو موافق موسم میں زمین میں ڈالنے اور پودا نکلنے کے بعد اس کی نگرانی کرنے اور اس کو آبپاشی کا مناسب انتظام کرنے جیسے سارے مفاہیم بھی پوشیدہ ہیں اوریہ سب عمل کے متقاضی ہیں۔ خواب وخیال سے نہ فصل بوئی جاتی ہے اور نہ کاٹی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مدار ومرکز آخرت ہی ہوتا ہے اور ہوناچاہیے۔ آخرت میں جزا وسزا پانے کے حوالے سے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:
فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْراً یَرَہُ۔ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ شَرّاً یَرَہُ ۔ ﴿الزلزال:۷،۸﴾
’’جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیاوہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا وہ اس کو دیکھ لے گا‘‘۔ ﴿ اس کا بدلہ پائے گا﴾
انسان چونکہ خیر وشر کا مجموعہ ہے، اس لیے دونوں کے انجام سے آگاہ کیاگیا اور بلاشبہ انسان اپنے اعمال کے مطابق یا خیر کا مشاہدہ کرے گا یا اسے شر لاحق ہوگا ۔ قرآن مجید میں صرف جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں کیاگیا ہے، بل کہ جہنم کی ہولناکیوں اور دردناک عذابوں کا بھی تذکرہ کیاگیا ہے۔ خود جہنم اور اس کے مترادف الفاظ مثلاً نار ﴿آگ﴾ جحیم اور سعیر وغیرہ سیکڑوں مرتبہ وارد ہوئے ہیں جو اپنی دردناکی اور ہولناکی پر خود دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ تصور انسان کو آمادہ عمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بے عملی اور بدعملی کی صورت میں جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَمَنْ أرَادَاْلاٰخِرَۃَ وَسَعیٰ لَہَا سَعْیَہَا وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلٰئِٓکَ کَانَ سَعْیُہُمْ مَشْکُوْراً۔ ﴿الاسرائ:۱۹﴾
’’اور جو آخرت کاخواہش مند ہو اوراس کے لیے سعی ﴿کوشش﴾ کرے جیسا کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور وہ مومن ہوتو ایسے شخص کی سعی مشکور ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا‘‘۔
قرآن حکیم میں وارد ہے قیامت میں جب لوگ جہنم میں چیخ پکار مچائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیامیں بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک اعمال کرلیں اور اس عذاب سے چھٹکارا پاجائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ انھیں کہے گا کہ کیا ہم نے تمھیں ایک مدت عمر عطا نہیں کی تھی کہ اس دوران میں تم نصیحت حاصل کرلو مزید یہ کہ ہم نے تمھیں سمجھانے ، ڈرانے والے بھی بھیجے۔ مگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی اور عمل کو درست نہیں کیا۔ ارشاد ہے:
أَوَلَمْ نُعَمِّرْکُم مَّا یَتَذَکَّرُ فِیْہِ مَن تَذَکَّرَ وَجَآئ کُمُ النَّذِیْرُ ۔﴿فاطر:۳۷﴾
’’کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمھارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا‘‘۔
یعنی تمھیں کام کرنے کا موقع دنیا ہی میں دیاگیا تھا مگرتم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
عقیدۂ رسالت اور زندگی کا حرکی تصور
رسولﷺ کی موجودگی میں رسالت پر ایمان کے جو محرکات ہوتے ہیں، ان میں دو خاص طور سے اہم ہیں۔ ایک رسول ﷺ کی سیرت وکردار جس کو دیکھ کر آدمی صدق و کذب کا فیصلہ کرتا ہے یا کرسکتا ہے اور دوسرا معجزات جن سے رسول ﷺ کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج چودہ سو تیس سال ﴿۱۴۳۳ھ﴾ کے بعد ہمارے سامنے نہ بہ ذات خود رسول موجود ہیں کہ ان کی سیرت وکردار کا ہم مشاہدہ کریں اور ان کی سچائی اور صدق کو پرکھیں اور نہ ہمارے سامنے ایسے معجزات ظاہر ہونے والے ہیں جیسے عہد رسالتﷺ میں رسالت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور جن کو دیکھ کر انھوں نے آپﷺ کو برحق اور صادق تصور کیا۔ اس تمہید کی روشنی میں آج امت مسلمہ کی ذمے داری دوہری ہوجاتی ہے کہ وہ نہ صرف آپﷺ پر اور آپﷺ کی رسالت پر ایمان لائے بل کہ ایسا کردار اور اخلاق کا نمونہ پیش کرے جو آپﷺ کی سیرت و کردار کے مثل ہو۔ بل کہ آپﷺ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اگرچہ غیر رسول صاحب معجزہ نہیں ہوسکتا مگر سیرت کا نمونہ و پیش کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز قرار دیاگیا ہے اور آپﷺ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے اسوہ قرار دیاگیا ہے۔ ارشاد ہے:
لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُولِ اللَّہِ أُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ ۔ ﴿الاحزاب:۲۱﴾
’’تمھارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے‘‘۔
’’ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رسول کو معجزہ دیاگیا جس کو دیکھ کر اس کی امت ایمان لاتی تھی ، مجھے بھی معجزہ دیاگیا اور وہ قرآن مجید ہے ۔ امید ہے کہ میری امت سب سے زیادہ ایمان لانے والی ہوگی‘‘۔﴿بخاری کتاب فضائل القرآن، باب کہف نزول الوحی﴾
ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے: ’’حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے دریافت کیاگیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو انھوں نے جواب دیا :آپﷺ کے اخلاق قرآن تھے ’’ قرآن میںدی گئی تمام اخلاقی تعلیمات کے گویا آپﷺ مجسم پیکر تھے۔ اس طور سے دیکھیں تو آج ہمارے سامنے رسولﷺ بھی موجود ہیں اور رسولﷺ کا معجزہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانے والی احادیث کا مستند ذخیرہ اور سیرت پر مشتمل سیکڑوں کتب ہمیں چلتے پھرتے رسولﷺ کا تصور دیتی ہیں ، جن سے آپﷺ کے ایک ایک عمل، حرکت ، قول ، فعل اور آپﷺ کی ایک ایک خواہش اور تمنا ہمارے سامنے موجود ہے۔ ضرورت صرف اس کی پیروی اختیار کرنے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں درجنوں مرتبہ اطیعواللہ اوراطیعوالرسول سے اہل ایمان کو خطاب کیاگیا ہے کہ وہ اطاعت الٰہی کے ساتھ اطاعت رسولﷺ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام ایک عملی دین ہے اور اس کے تقاضے عمل ہی سے پورے ہوتے ہیں۔ مسلمان عقیدۂ رسالتﷺ پر چاہے جتنی دلیلیں پیش کرلیں وہ قابل التفات نہیں ہوسکتیں۔ جب تک کہ وہ خود کو سیرت رسولﷺ کا نمونہ بناکر نہ پیش کریں۔مسلم شریف کی کتاب الطہارۃ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ
ﷺ کے بعد آئیں گے اور آپﷺ کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے اورآپﷺ کی سنتوں کی پیروی کریں گے۔
تقدیر اورحرکیت
عقیدے کاایک جزو تقدیر پر ایمان لانا ہے ۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر پہلے سے طے کردی ہے جس کے مطابق اس کی زندگی اور موت، روزی روٹی اور سعادت شقاوت طے شدہ امور ہیں۔ عام طور پر تقدیر کو بے عملی اور غیر فعالیت کے لیے بہانہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن وحدیث کے نصوص سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے ۔ تقدیر کے بارے میں یہ رویہ صحیح اور مبنی برحق ہے بل کہ قرآن وحدیث میں عمل پر ابھارا گیا ہے اور عمل کو بھی تقدیر قرار دیاگیا ہے۔ سابقہ امتوں اور قوموں کے تذکرے میں ان کے انعام یاعذاب کا تذکرہ عمل اور ان کے کرتوت کے پس منظرہی میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر معذب قوموں کے حوالے سے کہا گیا۔
ذٰلک جزیناہم ببغیہم۔ ﴿الانعام: ۱۴۶﴾
’’یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی‘‘۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
فَکُلّآً أَخَذْنَا بِذَنبِہِ فَمِنْہُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْہِ حَاصِباً وَمِنْہُم مَّنْ أَخَذَتْہُ الصَّیْْحَۃُ وَمِنْہُم مَّنْ خَسَفْنَا بِہِ الْأَرْضَ وَمِنْہُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا کَانَ اللَّہُ لِیَظْلِمَہُمْ وَلَکِن کَانُوا أَنفُسَہُمْ یَظْلِمُونَ ۔﴿العنکبوت:۴۰﴾
’’پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کرلیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا ۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبودیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے بل کہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے‘‘۔
اس کے برعکس نیک لوگوں کے حوالے سے ان کے اچھے اعمال پر اچھے اجر کا بھی تذکرہ کیاگیا ہے۔ چنانچہ جنت میں جانے والوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے اعمال ایسے تھے اس بنا پر ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوا۔ ارشاد ہے:
کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیْئآً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِیْ الْأَیَّامِ الْخَالِیَۃِ۔﴿الحاقہ: ۲۴﴾
’’مزے سے کھائو پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں‘‘۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
وَتِلْکَ الْجَنَّۃُ الَّتِیْ أُورِثْتُمُوہَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ﴿الزخرف:۷۲﴾
’’یہ وہ جنت ہے جس کا تمھیں وارث بنایا گیا ہے اس چیز کے بدلے جو تم کرتے تھے‘‘۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں تقدیر کے متعلق بعض اشکالات کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا: ’’عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ اہل سعادت کو سعادت کے باعث اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے اور اہل شقاوت کو شقاوت کے باعث اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے‘‘۔ ﴿مسلم کتاب القدر باب۱، حدیث نمبر ۶۷۳۱﴾
عمل صالح کا زندگی پر اثر
اسلام میں نجات وفلاح کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا گیا ہے۔ جبکہ سابقہ مذاہب میں اس بارے میں افراط وتفریط پائی جاتی ہے۔ عیسائیت میں صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے جیسا کہ کتاب مقدس میں پال کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بودھ مذہب میں صرف نیکوکاری سے نروان ﴿نجات﴾ کا درجہ ملتا ہے۔ بعض مذاہب میں محض گیان ودھیان کو نجات کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ مگر اسلام نے ایمان فکر وعقیدہ اور عمل ﴿جسمانی اعمال﴾ دونوں کو ایک ساتھ نجات کے لیے ضروری قرار دیا ہے ۔ چنانچہ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں جہاں ایمان لانے یا ایمان والوں کی کامیابی کا تذکرہ ہوا ہے وہاں عمل صالح کرنے یا عمل صالح کرنے والوں کی کامیابی کو ایک ساتھ بیان کیاگیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَالْعَصْرِ انَّ الْانسَانَ لَفِیْ خُسْر الَّا الَّذِیْنَ اٰ مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ﴿العصر:۳۔۱﴾
’’قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے‘‘۔
جنت کا حصول قومیت اور نسل پر موقوف نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ ارشاد ہے:
انَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُواْ وَالَّذِیْنَ ہَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَی مَنْ اٰ مَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْْہِمْ وَلاَ ہُمْ یَحْزَنُون۔﴿مائدہ:۶۹﴾
’’بے شک جو ایمان والے ہیں اور جو یہود ہیں اور صائبین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کرلے نہ تو ان پر ڈر ہے نہ وہ غم کھائیں گے‘‘۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مادی علل و اسباب کے تابع قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر روٹی بھوک کا قطعی علاج ہے۔ محض اس عقیدے سے بھوک نہیں مٹ سکتی جب تک اس کے لیے جدوجہد کرکے روٹی حاصل نہ کیا جائے اور اس کو چباکر اپنے پیٹ میں منتقل نہ کیا جائے بھوک نہیں مل سکتی۔ اسی طرح یہ تصور کہ ٹانگیں منزل تک پہنچے کا ذریعہ ہیں ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی ٹانگوں کو حرکت نہ دیں اور چلنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔
عمل صالح کی مختلف صورتیں ہیں اور اس میں کافی وسعت ہے۔ انسان کے تمام اعمال خیر کے تمام جزئیات اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ جس میں خدا کے تئیں اچھے کام بھی داخل ہیں اور بندوں کے تئیں اچھے کام بھی داخل ہیں۔ اس طور سے اس کی تین بڑی شکلیں بنتی ہیں۔ عبادات ﴿حقوق اللہ﴾ اخلاق و معاملات ﴿حقوق العباد﴾ اسلام میں ان میں سے ہر ایک کی یکساں اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں عبادت الٰہی کی تاکید آئی ہے وہیں اعمال خیر بجا لانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ۔ ﴿الحج:۷۷﴾
’’اے لوگو! جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو ، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو ۔ اسی سے توقع کی جاسکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔
عبادات میں حرکیت کے پہلو
مختلف مذاہب میں عبادت کی شکلوں پر غور کریں تو ان میں یا تو افراط و تفریط ہے یا جمود وتعطل کی تعلیمات ہیں۔ دنیا کے اکثر مذاہب نے خدا کو پانے کے لیے دنیا سے قطع تعلق کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان کے ماننے والوں نے پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں اور غاروں کا رخ کیا۔ اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈالا اور اس کو قرب الٰہی کا ذریعہ سمجھا یا مظاہر قدرت کی سجدہ ریزی اختیار کرلی اور توہمات کے شکار ہوگئے، بعض مذاہب میں محض چند رسوم و رواج کی پابندی کو عبادت قرار دیاگیا۔ بعض مذاہب میں معبود کے سامنے ناچنے ، گانے اور ڈھول اور ناقوس بجانے یااگربتی و موم بتی جلانے کو عبادت سمجھاگیا۔ غرض کہ مختلف مذاہب میں عبادت کی جو شکلیں ہیں ان سے نہ فرد کی ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی ترقی ہوتی ہے نہ دوسرے افراد کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام نے عبادات کی جو شکلیں بتائی ہیں ان میں سے ہر شکل میں کسی نہ کسی پہلو سے فرد یا معاشرے کی روحانی، ذہنی اورجسمانی ترقی ہوتی ہے یا معاشرے کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ اسلام نے عبادت کے تنگ مفہوم کاازالہ کرکے وسیع مفہوم دیا۔ عبادت کے لفظی معنی عاجزی اور درماندگی کے اظہار کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں خدائے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجالانا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں عبادت کو کبر کے مقابلے میںاستعمال کیاگیاہے۔ ارشاد ہے:
انَّ الَّذِیْنَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُونَ جَہَنَّمَ دَاخِرِیْن ﴿مومن:۶۰﴾
’جومیری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہوکر جائیں گے۔‘
ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہے:
وَمَنْ عِندَہُ لَا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِہ ﴿الانبیاء:۱۹﴾
’جو اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے۔‘
عاجزی و درماندگی سچے مومن کی بنیادی صفت ہے۔ ارشاد ہے:
اَّمَا یُؤْمِنُ بِاٰ تِنَا الَّذِیْنَ اذَا ذُکِّرُوا بِہَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّہِمْ وَہُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ ﴿السجدہ:۱۵﴾
’میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جن کو ان آیتوں سے سمجھایاجائے تو وہ سجدے میں گرپڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔‘
اسلام نے عبادت کاجو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے۔ اس میں کسی خاص کام اور طرز کی تخصیص نہیں ہے۔ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود اللہ کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی پیروی ہے ، عبادت ہے۔ اگرکسی نے اپنی شہرت کے لیے خزانہ بھی لٹادیا تو وہ عبادت نہیں، لیکن اگر اللہ کی خوش نودی کے لیے چند سکّے بھی کسی کو عطا کردیے تو بڑی عبادت ہے۔ اسلام کی اسی تعلیم نے عبادت کو دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بتایا۔ اسلام میں خدا کے لیے کام کرنا مطلوب ہے خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی بیان کی جائے یا کسی انسان یا حیوان کے فائدے کے لیے کام کیاجائے۔ چناںچہ اس تعریف کی رو سے خدمت خلق کے تمام کام عبادت کے مفہوم میں آتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں اس کی اہمیت پر واضح حکم موجود ہے۔ ارشاد ہے:
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَۃٌ خَیْْرٌ مِّن صَدَقَۃٍ یَتْبَعُہَا أَذًی وَاللّہُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ ﴿البقرہ: ۲۶۳﴾
’اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو۔‘
ایک اور حدیث میں غریب اور بیوہ کی مدد کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیاگیاہے۔
الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ ﴿بخاری کتاب الادب باب الساعی علی الارملۃ﴾
’بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے والے کا مرتبہ اللہ کے نزدیک جہاد کرنے والے کے برابر ہے اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نفل نماز پڑھتا ہو۔‘
ایک دوسری روایت میں دومسلمانوں کے درمیان بغض وعداوت کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کو بھی نماز اور روزے کے مثل قرار دیاگیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:
الااخبرکم بافض من درجہ الصیام والصلوٰۃ والصدقۃ قالوا قال اصلاح ذات البین ﴿ابوداؤد، کتاب الادب باب اصلاح ذات البین﴾
’کیا میں تم کو ﴿نفل﴾ روزہ ،نماز اور صدقے سے بھی بڑھ کر درجے کی چیز نہ بتائوں، صحابہؓ نے عرض کیا: ضرور بتائیے۔ آپﷺ نے فرمایا: وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے۔‘
ایک حدیث میں وارد ہے:
’قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ میں بیمار ہوا مگرتو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکاتھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس کے جواب میں بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو تو رب العالمین ہے تو کیسے بیمار ہوسکتا ہے یا تجھے بھوک و پیاس لگ سکتی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا،مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تونے ایسا کیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی میری خوش نودی تمھیں وہاں ملتی۔‘
اسلام میں عبادات کی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے ہر شکل میں حرکیت کے مخصوص اور نمایاں پہلو پوشیدہ ہیں۔
نماز اور حرکیت
انسان کی بندگی کے اظہار اوراللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے اقرار کا سب سے جامع طریقہ نماز ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کے اقرار کے بعد جوارح سے اس کے ثبوت کے لیے نماز سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دن اور رات میں کم ازکم پانچ بار انتہائی مناسب اوقات میں بندے کو معبود سے جوڑتا ہو۔ اسلام نے نماز کے ذریعے سے بندے کو جوڑے رکھنے کا طریقہ بتایاہے۔ خاص طور سے اگر نماز کے ارکان اور اوقات کا گہرائی سے مطالعہ کیاجائے تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ نماز عبادت کی وہ شکل ہے جس سے بندہ معبود کے تعلق سے کبھی غفلت اور تساہلی میں مبتلا نہیں ہوپاتا۔ ہمہ وقت وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں پانچ نمازوں کاتذکرہ اس طرح کیاگیا ہے:
أَقِمِ الصَّلاَۃَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ اٰی غَسَقِ اللَّیْْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ انَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُوداً ﴿الاسراء:۷۸﴾
’آفتاب کے جھکائو کے وقت سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو اور فجر کی قرأت قائم کرو، فجر کو قرأت میں حضور ﴿دل کا اور فرشتوں کا﴾ ہوتا ہے‘
آفتاب کے جھکاو ﴿دلوک﴾ کی تین شکلیں ہیں۔ زوال کے وقت ایک جھکائو ہوتاہے، مقابل نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر دوسرا جھکائو ہوتاہے اور غروب پر تیسرا جھکاو ہوتاہے۔ ان تینوں جھکاو میں تین نمازیں ظہر، عصر اور مغرب مشروع ہیں۔ ’غسق اللیل‘ سے عشا کی نماز مراد ہے اور ’قرآن الفجر‘ سے فجر کی نماز مراد ہے۔انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس کی زندگی جاری و ساری نہیں رہ سکتی۔ ایک کسب معاش کی ضرورت ہے اور دوسری نیند اورآرام کی۔ دونوں ضرورتوں کے لیے مناسب وقفے کی حاجت ہے۔ چنانچہ فجر سے ظہر تک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عشا سے فجر تک بھی طویل وقفہ ہے۔ ان اوقات میں فرض نماز نہیں ہے۔ تاکہ انسان کی یہ دونوں فطری ضرورتیں بدرجہ اتم پوری ہوں۔ مگر یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے سبب عام طور سے غفلت اور کاہلی طاری ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے آغاز واختتام پر نماز مشروع کی گئی تاکہ یاد الٰہی سے قلب و ذہن تازہ ہوجائے۔ شام کے اوقات عموماً اضمحلال اور تھکاوٹ کے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے نماز یں متعین کی گئیں۔ تاکہ اِنسان پر مکمل طور سے سستی اورکاہلی طاری نہ ہوجائے۔
ارکانِ نماز بھی حرکیت کا سبب ہیں۔ عبادت بنیادی طورپرذکرالٰہی کا نام ہے، جس کاذریعہ قلب اورلسان ہیں۔ نماز میں زبان اور دل سے ذکر کے ساتھ قیام، رکوع اور سجدے کی شکلیں ذکر الٰہی کو جامعیت عطا کرتی ہیں۔ پھر جماعت اور وقت کی پابندی سے وحدت اور یکسانی کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ گویا نماز عبادت کی ایسی جامع شکل ہے جس میںدل، زبان، جسم اور فرد اور اجتماعیت سب شامل ہوجاتے ہیں۔
زکوٰۃ کا زندگی سے ربط
عبادت کی دوسری اہم قسم زکوٰۃ ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی۔ جس سے معاشی طورپر معاشرے کے کم زور اور پس ماندہ طبقات کی کفالت ہوتی ہے۔ نماز حقوق اللہ کا عنوان ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد کا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآنی آیات اور احادیث رسول کامطالعہ کیا جائے تو یہ بات بہت واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسولِ کریم نے زکوٰۃ دینے پر ابھارا ہے، لینے پر نہیں ابھارا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں لینے والوں کی نہیں بیان کی گئی ہیں۔ درآں حالے کہ قرآن مجید اور احادیث میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ زکوٰۃ دے کر اس کی عبادت کی ادائی کا ثواب حاصل کیاجائے احتیاج میں مبتلا رہنے کے بجائے مطلوبہ نصاب کے حصول کے لیے کسب معاش کی جدوجہد کی جائے۔ قرآن مجید میں ۳۲مرتبہ ’نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو‘ کے مفہوم کاجملہ وارد ہے۔ اس کے علاوہ عام صدقات کا بھی حکم دیاگیا ہے۔ مزید یہ کہ نذر اور وصیت کی صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ان سب سے معلوم ہوتاہے کہ اسلام مالی طورپر آدمی کو دینے والے کی پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے نہ کہ لینے والے کی پوزیشن میں۔
نصاب زکوٰۃ پرغور کیاجائے تو اس سے بھی معلوم ہوتاہے کہ اس میں فرد اور معاشرے کے حرکی تصور کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مال کے بنیادی طورپر تین سرچشمے ہیں: سونا چاندی، مویشی اور اجناس غذائیہ ﴿اناج﴾۔ زکوٰۃ انھی تینوں اجناس پر واجب ہے۔ موجودہ دور میں سونا چاندی کا بدل کرنسی اور روپیہ ہے۔ فرد کی مال داری کااعتبار سال گزرنے پر کیاگیا ہے ۔ تاکہ اس کا مالی طورپر مستحکم ہونا یقینی ہوجائے۔ ہر جنس مال پر زکوٰۃ کی مقدار الگ الگ ہے۔ تاکہ ان کی فطری نموو ارتقا کی رفتار، مالیت اور مقدار کا لحاظ کیاجاسکے۔ مثال کے طورپر اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ کی مقدار میں فرق ہے۔ پانچ اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہے اور چالیس بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کی الگ الگ مقدار مقرر کی گئی ہے۔ کیوںکہ دونوں کی قدر الگ الگ ہے۔ اجناس غذائیہ میں پانچ وسق ﴿ایک وسق ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر﴾ مقدار کا تعین ہوا، تاکہ زکوۃ دینے والا پہلے خودکفیل ہوجائے پھر وہ دوسرے کی امداد کرے۔ زمینی پیداوار میں نظام آب پاشی کا بھی لحاظ کیاگیا ہے۔ اگر آسمانی بارش سے فصل تیار ہوتو عشرہے ﴿۱۰/۱﴾ لیکن اگر نہر یا کنویں سے آب پاشی کی گئی ہوتو عشرکی نصف ﴿۲۰/۱﴾زکوٰۃ ہے۔مصارف زکوٰۃ میں ایک طرف سماج کے کم زور اور محتاج طبقوں کو اولیت دی گئی تاکہ ان کی معاشی حالت درست ہوجائے۔ دوسری طرف مصارف کو آٹھ قسم کے لوگوں میں محدودکرکے مفت خوری اور پیشہ ورانہ گداگری کا انسداد کیاگیا۔ گویا دونوں پہلوئوں سے شریعت اسلامیہ نے معاشرے کی بہتری کو ملحوظ رکھا۔ مال داروں پر زکوٰۃ فرض کرکے مال کی محبت اور حرص کا خاتمہ کیاگیا۔ اسی طرح مال کے لالچ میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مذمت کی۔
روزہ اور حرکیت
انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم اور روح۔ جس طرح جسم پر مختلف قسم کی بیماریاں حملے کرتی ہیں اور اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح پر بھی مختلف قسم کی بیماریاں حملے کرتی ہیں اور اس کو ان سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم کی بیماریوں کو امراض الابدان کے نام سے جانا جاتا ہے اور روحانی بیماریوں کو گناہوں اور خطائوں، اثم ذنب، سئیہ، منکر، فحش اور جرم جیسے دوسرے ناموں سے جانا جاتاہے۔ روزہ بیک وقت جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں کے لیے احتیاطی تدابیر کااعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں روزے کے مقصد میں تقویٰ ﴿خوف خدا﴾ کو اولیت دی گئی ہے اور حدیث شریف میں اس کو ڈھال ﴿الصیام جُنّۃ﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
انسانی زندگی میں شہوت فرج ﴿جنسی خواہش﴾ اور شہوت بطن ﴿کھانے پینے کی خواہش﴾دو ایسی شہوات ہیں جو انسان کو بد سے بدتر اعمال پر آمادہ کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرلیتاہے۔ روزے کی عملی شکل میں کھانے پینے اور جنسی خواہش کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے تاکہ ایک محدود وقت میں ان پر قابو پانے کی مشق سے طویل وقفے میں اِنسان غلط کاری سے بچنے کی کوشش کرے۔
انسان کی روحانی ترقی اور ارتقا میں نفسانی خواہش سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشوںپر قابو پالے تو فرشتوں کے مثل ہوجائے۔ ایک محدود وقت تک ان پر قابو پانے کی نیت و ارادہ اس پر مکمل طریقے سے قابو پانے پر آمادہ کرتا ہے اور اس میں اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقا ہوتاہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات اکل و شرب اور جنسی خواہش سے بے نیاز ہے، اس طرح فرشے اکل و شرب اور خواہشوں سے مبرّا ہیں۔ انسان روزے کے ذریعے سے اپنے اندر انھی صفات اور ملکوتی اوصاف کوپیدا کرکے اپنی روحانیت کو جلا دیتا ہے۔
انسانی جسم میں نظام ہضم، دوران خون، اعصابی نظام اور خون کی پیداوار یہ اہم ترین حصے اور اعمال ہیں۔ اور کھانے پینے اور جنسی خواہش سے ان پر سخت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر حالات میں جسم میں یہی حصے اور اعمال بیماریوں کی آماج گاہ ہیں۔ روزے سے خاص طورپر ان نظاموں اور اعمال پر نہایت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گویا سال میں ایک ماہ کے روزے جسم انسانی کی مرمت کا کام بھی کرتے ہیں۔ روزے کی اس روحانی اور جسمانی افادیت کے ساتھ یہ غریبوں اورمفلسوں سے موانست کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔
حج اور حرکیت
حج کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ یہ جسمانی ومالی دونوں سے مرکب عبادت ہے۔ اس لیے اس میں استطاعت ﴿صحت ومال﴾ کی قید لگائی گئی ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مناسک حج کی ادائی دور دراز سفر طے کرنے کے بعد مکہ شریف میں ہوسکتی ہے۔ سفربجائے خود حرکت کا موجب ہے۔ حج کے ارکان، طواف کعبہ، سعی صفا ومروہ، قیام عرفہ، منیٰ، قربانی وغیرہ حرکت و عمل کے بغیر انجام نہیں دیے جاسکتے۔ پھر ساری دنیا سے الگ الگ رنگ ونسل، زبان وقومیت اور تہذیب و ثقافت پر مشتمل انسانو ں کی یکجائی اور مناسک حج کی ادائی وحدت انسانی اور مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، جس سے نہ صرف مکہ مکرمہ میں بل کہ تمام دنیا میں انسانیت کو وحدت و مساوات کاپیغام ملتا ہے۔
حج کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ماضی سے انسان کا رابطہ کئی پہلوئوں سے مفید ہے۔ آج سے پانچ ہزار سال قبل کے عہد کے طریقِ عبادت کی یادگار کی عملی یاد دہانی انسانیت کی روحانی ترقی کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخی مظاہرے متحرک و فعال کرتے ہیں۔ حج کے مقامات و ارکان کو شعائر کہاگیا ہے:
انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَۃَ مِن شَعَآئِرِ اللّٰہ ﴿البقرہ:۱۵۸﴾
’بے شک صفا و مروہ خدا کے نشانات ﴿شعار﴾ ہیں‘
مکہ مکرمہ کی نسبت نہ صرف حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیلؑ اور ان کی اماں حضرت ہاجرہؑ سے بہت گہری ہے بل کہ اس کی حضرت آدم وحوا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری نسبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاے پیدایش اور اولین مہبط وحی بھی مکہ مکرمہ ہے۔ ایسی فضائوں میں جب حج کرنے والا اپنے کو پاتا ہے تو یقینی طورپر اس کے اندر دین کی نسبت گہری ہوجاتی ہے۔
حج کی حقیقت صرف چند جسمانی اور مادی رسموں کی ادائی ہی تک محدود نہیں ہے بل کہ ارکان حج ہمارے اندر داخلی احساسات و کیفیات کو متاثر کرتے ہیں ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو سراپا نیکی ﴿حج مبرور﴾ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حج توجہ انابت اور گزشتہ بیتی عمر کی تلافی اور آیندہ بہتر زندگی گزارنے کا عہدوقرار بھی ہے۔ جیساکہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے مترشح ہے:
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْْنِ لَکَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّۃً مُّسْلِمَۃً لَّکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْْنَا انَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْم ﴿البقرہ:۱۲۸﴾
’اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرماں بردار ﴿مسلم﴾ بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک فرمانبردار گروہ بنا اور ہم کو اپنے ﴿حج کے﴾ احکام اور دستور سکھا اور ہم پر رجوع ہو ﴿یا ہم کو معاف کردے﴾ تو بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔‘
حج کی ایک افادیت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کو ایک نیا موڑ ملتاہے اور یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی خاص واقعے، حادثے یا تاریخ کو اپنی زندگی کے لیے ایک موڑ سمجھتا ہے اور حد فاصل قرار دیتا ہے اور اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے۔ حج بھی ایسے ہی مواقع فراہم کرتا ہے کہ آدمی حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق کرے اور بعد کو پہلے سے بہتر بنائے۔ عام طورپر حاجی حج کے بعد اپنے کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں اور ان کی دنیا سے رغبت کم ہوجاتی ہے۔
گاؤں دیہات کا آدمی جس کی ذہنی سطح بہت پست ہوتی ہے وہ گائوں کے معاملات سے اوپر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ جان سکتاہے۔ حج کے دوران میں جب وہ دنیا بھر کے لوگوں کامشاہدہ کرتاہے تو نہ صرف اس کے دائرۂ مشاہدات میں وسعت پیداہوتی ہے بل کہ اس کے اندر عام انسانیت اور باہر کی دنیا کے معاملات سے بھی دل چسپی پیدا ہوتی ہے۔
حج عورتوں کے لیے بھی وسعت و فراخی پیداکرنے کا سبب ہے۔ عام طورپر عورتوں کی زندگی گھر کی چہاردیواری میں گزرتی ہے۔ لیکن حج میں اس کو دور دراز کے سفر کا موقع ملتاہے اور وہ کھلی فضا میں سانس لیتی ہے۔ چیزوں کامشاہدہ کرتی ہے اور دنیا کے مسائل کو جانتی اور سمجھتی ہے۔ اس سے عورتوں کا بھی ذہنی افق بلند ہوجاتاہے۔
اخلاقیات کا اِنسانی زندگی سے ربط
انسانی زندگی کا ایک دائرۂ عمل اخلاقیات ہے۔ اخلاق ہی سے انسان کے سلوک وبرتائو اور اس کی دوسرے کے لیے افادیت ظاہر ہوتی ہے۔ بل کہ اخلاق ہی آدمی کو حرکت و عمل کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات عیسائیت کے تصور رہبانیت اور ہندومت کے ترکِ دنیا ﴿جوگی پن﴾ سے یکسر مختلف ہیں ۔اسی طرح قدیم یونان کے ان دو فلسفیانہ تصورات سے بھی مختلف ہیں جن میں ایک کو ہنسنے والے فلسفی اور دوسرے کو رونے والے فلسفی کہاگیا ہے۔ ہنسنے والے فلسفی کے نظریے کے مطابق زندگی محض موج مستی کے لیے ہے جب کہ رونے والے فلسفی کے نظریے کے مطابق زندگی میں مایوسی اور ناامیدی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا خاموش رہو اور زندگی میں موت کی صورت بنالو کہ دنیا کی آخری منزل یہی ہے۔ اسلام میں اخلاقی تعلیمات ان دونوں نظریات کے درمیان نقطۂ اعتدال پر قائم ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا کی فنا و زوال کو آدمی کے ذہن سے فراموش نہیں ہونے دیتا۔ تاکہ وہ غفلت کا شکارنہ ہوجائے اور دوسری طرف وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونے دیتا اور اخیروقت تک اللہ تعالیٰ پر بھروسا قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے:
فَلاَ تَکُن مِّنَ الْقَانِطِیْن﴿الحجر:۵۵﴾ ’ناامیدوں میں سے نہ بن‘
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِہِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَۃِ اللَّہِ ﴿الزمر:۵۳﴾
’اے میرے بندو! جنھوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت بنو۔‘
اِسلام نے خلق سے تعلق ، جماعت سے وابستگی اور عزیز واقارب سے میل جول کی تلقین کی۔ اس پر پہنچنے والی ایذاء پر صبر کو عبادت اور رضائے الٰہی کا سبب قرار دیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:
ان المسلم اذا کان یخالط الناس ویصبر علی اذاھم خیر من المسلم الذی لایخالط الناس و لایصبر علی اذاھم۔
﴿جامع الترمذی، ابواب ضقہ القیام باب فضل المخالطۃ مع الصبر علی اذی الناس ۲۵۰۷﴾
’وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتاہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔‘
اسلامی اخلاقی تعلیمات کی طویل فہرست ہے، اس پر ایک نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتاہے کہ اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیمات کے ہر جز میں حرکی پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔ متعلقین کے حقوق کی ادائی حرکت و عمل کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح سخاوت و فیاضی، عدل و انصاف، احسان، عفو و درگذر، شجاعت وبہادری، استقامت، خودداری وعزت نفس، اعتدال ومیانہ روی، تواضع اور انکسار یہ ساری صفات اپنے مخصوص دائرے میں حرکت کی متقاضی ہیں۔ اخلاقیات کا ایک پہلو منفی اخلاق یا رذائل اخلاق کا ہے۔ اسلام نے ان کے بارے میں واضح تعلیمات دے کر انسان کو منفی سوچ اور منفی حرکت و عمل سے روکا ہے۔ ظلم وسرکشی، خیانت و غداری، چغل خوری، غیبت، دورخاپن، بدگمانی، چوری، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی ، رشوت خوری، شراب نوشی، بے جا غیظ وغضب، فخر و غرور، فضول خرچی، حسد وغیرہ جیسی تمام صفات آدمی پر منفی اثرات مرتب کرنے والی ہیں۔ اسلام نے ان سے روکا ہے۔ تاکہ ا س کا دائرۂ عمل منفی رخ پر سفر نہ کرے:
قُلْ اَمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْْرِ الْحَقِّ ﴿الاعراف:۳۳﴾
’اے پیغمبر! کہہ دیجیے کہ میرے پروردگار نے بُرائی کے سارے کاموں ﴿فواحش﴾ کو جو کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو منع کیاہے۔‘
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
وَلاَ تَمْشِ فِیْ الأَرْضِ مَرَحاً انَّکَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاًoکُلُّ ذٰلِکَ کَانَ سَیٍّئُہ‘ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوہاo﴿بنی اسرائیل:۳۷،۳۸﴾
’اور زمین میں اِتراکر نہ چل کہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ جائے گا، ان میں سے جوبُری بات ہے وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔‘
معاملات ِ زندگی اور حرکیت
اسلامی تعلیمات کا ایک شعبہ معاملات ہیں۔ اس سے مراد معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل ہیں۔ ان تینوں قسم کے مسائل کے بارے میںنہ صرف اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ بل کہ اس نے ان کا حرکی یعنی متحرک و فعّال تصور بھی پیش کیا ہے۔ مثال کے طورپر معاشرتی مسائل سے مراد نکاح وطلاق اور اہل و عیال اور خاندان کے متعلقین کے حقوق کی ادائی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے تجرد کی نفی کی اور نکاح کی ترغیب دی ہے۔ پھر نکاح نہ کرنے والے کو سنت محمدیﷺ سے اعراض کرنے والا قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ نکاح ایسی عورت سے کیاجائے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔میاں بیوی ان بچوں کی پرورش و پرداخت کے لیے تگ ودو کریں یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے نزدیک مطلوب ہیں اور اجرکی مستحق ہیں۔ اسی طرح اقتصادی مسائل میں خریدو فروخت ، لین دین، مختلف پیشوں کو اختیار کرنا اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا اور گداگری سے بچنا عین شریعت کی منشا ہے۔انسانی ضرورتیں اجتماع اور تعاون باہمی کے بغیر پوری ہوہی نہیں سکتیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ لوگ اکٹھا رہیں۔ پس جب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو لازم ہے کہ اجتماعیت چلانے کے لیے ایک نظم موجود ہو۔ چنانچہ اسلام نے اجتماعیت کو قائم کرنے اور اس کو باقی رکھنے کی واضح تعلیمات دی ہیں:
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّہِ جَمِیْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴿اٰل عمران:۱۰۳﴾
’اور سب سے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو اور تفرقے میں نہ پڑو۔‘
اسلام نے اجتماعیت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر تین لوگ ہوں اور سفر کی حالت میں ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک فرد کو اپنا امیر منتخب کرلیں اور اس کی اطاعت کریں۔‘ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
عن ابی سعید الخدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج ثلاثہ، فی سفر فلیؤمروا احدھم۔
﴿ابوداؤد، کتاب الجہاد باب فی القوم یسافروں یؤمرون احدھم﴾
’ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تین لوگ سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کرلیں۔‘
عام زندگی میں ایک مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اجتماعیت سے کٹ کر زندگی گزارے۔ اس میں خطرات اور اندیشے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
ترجمہ:’شیطان انسان کا بھیڑیا ﴿دشمن﴾ ہے جس طرح بھیڑیا تنہا اور الگ تھلگ پھرنے والی بکری کو اچک لیتا ہے ﴿اِسی طرح تنہا اور اجتماعیت سے الگ فرد کو شیطان ہلاکت میں ڈال دیتا ہے﴾ لہٰذا تم گروہ بندی سے بچو اور جماعت،عوام الناس اور مسجد کو لازم پکڑو۔‘ ﴿مسند احمد:۵/۲۳۳، ترمذی کتاب الفتن باب بذاع الجاقہ﴾
ایک اورروایت میں ارشاد نبویﷺ ہے:
’جس نے اطاعت ﴿امیر﴾ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے حجت نہیں ہوگی اور جو شخص اس حال میں مراکہ اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت ﴿کا قلادہ﴾نہیںتھا تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔‘
ایک طرف شریعت اسلامیہ نے فرد کو اجتماعیت سے وابستہ رہنے کی سخت تاکید کی تو دوسری طرف ارباب اقتدار کو عدل وانصاف اور رعایا کے ساتھ نصح و خیر خواہی کی تاکید کی اور اس بارے میں کوتاہی پر وعید سنائی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:
ترجمہ: ’جو امام و حاکم ضرورت مندوں سے اپنا دروازہ بندکرلیتاہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت آسمان کا دروازہ بندکرلے گا۔‘ ﴿ترمذی ابواب الاحکام باب ماجاء فی امام الدعیۃ﴾
ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکے اسلوب میں امت کے حوالے سے فرمایا:
’اے اللہ! جو کوئی میری امت کی کسی بات کا بھی والی ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کرنا اور جو ان سے مہربانی سے پیش آئے تو تو بھی اس پرمہربانی فرمانا۔‘ ﴿مسلم ، کتاب الدمارۃ، باب فضیلۃ الامام العادل﴾
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمرفاروقؓ کہاکرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہوجائے تو مجھے ڈرلگتاہے کہ اللہ مجھ سے بازپرس کرے گا۔﴿کنزالعال،۵/حدیث۲۵۱۵﴾
ان نصوص سے معلوم ہوتاہے کہ اسلام نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعیت تک ہر پہلو سے اپنے ماننے والوں کو ہمہ دم فعّال اور متحرک رکھنے کاسامان کیا ہے اور ایسی ہدایات دی ہیں جن سے آدمی کی انفرادی تزکیہ و تربیت ہونے کے ساتھ وہ معاشرے اور سماج کی تعمیر وترقی میں سرگرم کردار ادا کرتا ہے۔